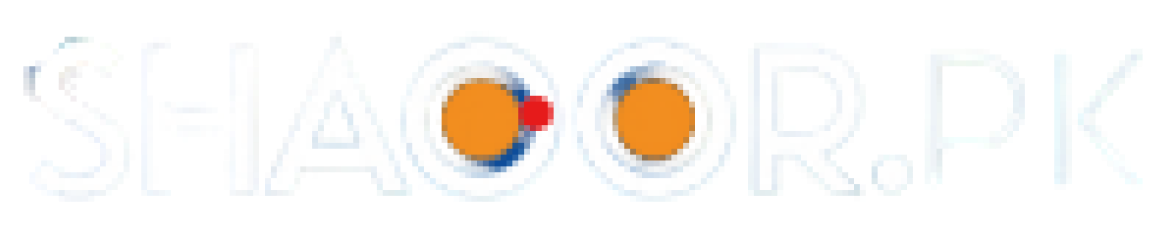![‘جدیدیت’ محمد حسن عسکری [2]](https://666b56dbb95b5a129f686328.metastore.ai/storage/shaoor_uploads/2019/04/6-2.jpg)
٭5۔عقلیت پرستی کا دور:
یہ دور تقریباً سترہویں صدی کے وسط سے شروع ہو کر اٹھارہویں صدی کے وسط تک یا ۱۷۷۵ء تک چلتا ہے۔ ۱۷۵۰ء کے قریب ایک دوسرا رجحان جذبات پرستی کا شروع ہوچکا تھا۔
جدوجہد کا اصل میدان: مادی کائنات
عقلیت پرستی کی داستان یہ ہے۔ سترہویں صدی کے وسط تک لوگ یہ طے کرچکے تھے کہ انسان کی جدوجہد کا میدان یہ مادی کائنات ہے اور انسان کا مقصدِ حیات تسخیرِ فطرت یا تسخیر کائنات ہونا چاہیے۔ بیکن نے مطالعۂ فطرت کا طریقہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں سے کون سی صلاحیت ایسی ہے جو تسخیر کائنات کے لیے زیادہ مفید ہوسکتی ہے۔ اس دور نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان صرف عقل <یعنی عقل جزوی اور عقلِ معاش>undefined پر بھروسہ کرسکتا ہے کیونکہ یہی چیز سارے انسانوں میں مشترک ہے۔
لفظ یونیورسل اور جنرل کا فرق:
عقل <جزوی>undefined کا یہ اختصاص ظاہر کرنے کے لیے ان لوگوں نے لفظ Universal استعمال کیا۔ اس لفظ کی وجہ سے اتنی غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہمارے علماء کو اس کی نوعیت اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں ’’عالم گیر‘‘ یا ’’کائنات گیر‘‘۔ مگر یہاں عالم کے معنی مادی کائنات نہیں ہیں، بلکہ وہ مفہوم ہے جو ’’اٹھارہ ہزار عوالم‘‘ کے فقرے میں آتا ہے۔ ہمارے دینی علوم میں، دراصل اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ۔’’کامل‘‘ <جیسے ’’انسانِ کامل‘‘>undefined اور ’’کلی‘‘ <جیسے ’’عقلِ کلی‘‘>undefined۔ مگر فی الحال مغرب ’’عوالم‘‘ کا مطلب نہیں جانتا، اس کے ذہن میں ’’عالم‘‘ کا مطلب صرف مادی کائنات اور اس کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ سترہویں صدی سے مغرب میں Universal کا لفظ General <یعنی عمومی>undefined کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ جو چیز ’’عمومی‘‘ ہوتی ہے وہ انفرادیت اور جزویت ہی کے دائرے میں رہتی ہے، ’’کامل‘‘ اور ’’کلی‘‘ نہیں ہوتی۔ مگر مغرب اس امتیاز سے واقف نہیں۔
یہ تو جملۂ معترضہ تھا۔ غرض، عقلیت پرستی کے دور میں یہ بات تسلیم کرلی گئی کہ انسان کی رہنمائی بس عقل <جزوی>undefined کرسکتی ہے۔
دیکارت اور نیوٹن کی گمراہیاں:
اس دور کے سب سے بڑے ’’امام‘‘ دو ہیں ایک تو فرانس کا فلسفی اور ریاضی دان دے کارت (Descartes) اور دوسرا انگلستان کا سائنس دان نیوٹن۔
دیکارت یوں تو رومن کیتھلک پادری تھا، اور اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کر کے اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ مغرب کے ذہن کو مسخ کرنے کی ذمہ داری جتنی اس پر ہے شاید اتنی کسی ایک فرد پر نہیں۔ فرانس کے ایک رومن کیتھلک مصنف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ فرانس نے خدا کے خلاف جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکارت کو پیدا کیا۔
روح اور مادے کی تقسیم:
اب تک تو یہ بحث چلی آ رہی تھی کہ حقیقت روح میں ہے یا مادے میں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ روح حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مادہ بھی حقیقت رکھتا ہے مگر ظّلی طور پر۔ کچھ لوگ دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے تھے کہ بس مادہ ہی حقیقت ہے۔ اس سارے جھگڑے کا دیکارت نے یہ حل نکالا کہ روح اور مادہ دونوں حقیقی ہیں، مگر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ چنانچہ اس نے روح اور مادے کو، انسان کی روح اور جسم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جو ایک دوسرے سے آزاد اور خود مختار ہیں۔
مغربی فلاسفہ: جسم و مادہ سے اوپر نہ جاسکے
یہ نظریہ مغربی ذہن میں اس طرح بیٹھا ہے کہ تین سو سال سے یہ تفریق اسی طرح چلی جا رہی ہے، روح اور جسم، روح اور مادے کے ارتباط کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا۔ مغرب کے زیادہ تر مفکر جسم اور مادے میں اٹک کے رہ گئے، اس سے اوپر نہیں جاسکتے۔ کچھ مفکر روح میں لٹک گئے تو نیچے نہیں آسکتے۔ دیکارت کے فلسفے کا سب سے خوفناک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مغرب ’’روح‘‘ کے معنی ہی بھول گیا اور ’’ذہن‘‘ <یا ’’نفس‘‘>undefined کو روح سمجھنے لگا۔
یونانی تصور انسان: معاشرتی یا عقلی حیوان:
یہ گڑ بڑ دراصل یونانی فلسفے میں بھی موجود تھی۔ ارسطو وغیرہ یونانی فلسفی انسان کی تعریف دو طرح کرتے ہیں۔ انسان کو یا تو ’’معاشرتی حیوان‘‘ کہتے ہیں یا ’’عقلی حیوان‘‘۔ <ان فقروں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یونانی فلسفے پر معاشرتی نقطۂ نظر اور عقلِ جزوی کس حد تک غالب تھی۔>undefined دیکارت کے ہم عصر فرانسیسی مفکر پاسکال (Pascal) نے انسان کو ’’سوچنے والا سرکنڈا‘‘ (Thinking Reed) بتایا ہے ۔ یعنی انسان کے جسمانی وجود کو جانور کی سطح سے بھی نیچے اتار دیا ہے۔ <مغرب کی ساری جسم پروری کے باوجود مغربی فکر میں جسمانیت سے گھبرانے اور اسے حقیر سمجھنے کا رجحان بھی خاصا قوی ہے>undefined۔
دیکارت کا فلسفہ: وجود کا انحصار ذہن پر ہے
اسی طرح دیکارت نے انسانی وجود کی تعریف ایک مشہور لاطینی فقرے میں یوں کی ہے:
Cogito ergo sum (I think therefore I am)
’’میں سوچتا ہوں، اس لیے میں ہوں‘‘
گویا اس کے نزدیک وجود کا انحصار ذہن پر ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی نہ سوچے تو اس کا وجود باقی رہے گا یا نہیں۔ خود دیکارت سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ ’’میرے کتے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟‘‘
مغربی فلسفے کی الجھن: کبھی دور نہیں ہوسکی
غرض، جسم اور روح، مادے اور روح کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکارت نے مغربی فکر کو ایسی الجھن میں ڈال دیا ہے جس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور مغربی ذہن ہر مسئلے پر روح اور مادے کے تقابل یا تضاد ہی کے لحاظ سے غور کرتا ہے۔
پاسکال: دل کی منطق عقل نہیں سمجھ سکتی
دیکارت کے ہم عصر پاسکال نے ایک دوسرے قسم کی کشمکش مغربی ذہن میں پیدا کی ہے۔ اب تک تو لڑائی روح اور جسم میں ہی تھی۔ چونکہ مغرب ’’روح‘‘ کے معنی بھولنے لگا تھا اس لیے کہنا چاہیے کہ ذہن <یا نفس>undefined اور جس میں لڑائی تھی۔ پاسکال نے اعلان کیا کہ ’’دل کے پاس بھی ایسی منطق ہے جسے عقل نہیں سمجھ سکتی‘‘
“The heart has reasons of its own which the Reason does not understand.”
ادیان مشرق: دل سے مراد عقل کلی
یہاں لفظ ’’دل‘‘ کے معنی خاص طور سے سمجھ لینے چاہئیں۔ نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ سارے مشرقی ادیان میں ’’دل‘‘ سے مراد ہے ’’عقلِ کلی‘‘۔ علاوہ ازیں ہمارے یہاں ’’نفس‘‘ روح اور جسم کے درمیان کی چیز ہے۔ اس لیے ’’نفس‘‘ میں عقلِ جزوی بھی شامل ہے اور ہوا و ہوس بھی۔ پاسکال نے جس ’’دل‘‘ کا ذکر کیا ہے اور جسے ’’ذہن‘‘ کے مقابل رکھا ہے اس سے مراد ’’جذبات‘‘ ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاسکال نے ’’دل‘‘ اور ’’عقل‘‘ یا ’’ذہن‘‘ کے درمیان جنگ چھیڑ دی اور مغربی فکر اور ادب میں اس جنگ کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ سے آدمی کو جذباتی تکلیف پہنچتی ہے۔
کرب اور مذہب ہم معنی ہوگئے
بیسویں صدی میں اس تکلیف کا نام ’’کرب‘‘ رکھا گیا ہے۔ <اس ضمن میں جرمن زبان کا لفظ Angst بہت مشہور ہوا ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ Anguish ہے>undefined ہمارے زمانے میں بہت سے مغربی مفکر اس ’’کرب‘‘ کو انسان کی معراج سمجھتے ہیں۔ دیکارت کہتا تھا کہ انسان کو وجود سوچنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کل کے بہت سے مفکر کہتے ہیں کہ انسان کو وجود ’’کرب‘‘ سے حاصل ہوتا ہے بلکہ بعض مفکر تو اس ’’کرب‘‘ اور مذہب کو ہم معنی سمجھتے ہیں اور اپنی دینیات کی بنیاد اسی پر رکھتے ہیں۔
نیوٹن:
عقلیت پرستی کے دور کا دوسرا بڑا امام نیوٹن ہے۔ سائنس میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ ’’کششِ ثقل کے قانون‘‘ کی دریافت ہے۔ لیکن مغربی ذہن پر اس کا اثر بہت گہرا پڑا ہے۔ یہ قانون معلوم کر کے اس نے گویا یہ دکھا دیا کہ کائنات کا نظام چند واضح قوانین کے ذریعے چل رہا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل <جزوی>undefined کی مدد سے یہ قوانین دریافت کر لے تو کائنات اور فطرت پر پورا قابو حاصل کرسکتا ہے۔ قوانین دریافت کرنے میں وقت لگے گا لیکن انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایک دن فطرت کو فتح کرلے گا۔
سائنس نیوٹن سے بہت آگے چلی گئی اور اس کا تصورِ کائنات رد کر دیا گیا، مگر اس نے جو ذہنیت پیدا کی تھی وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔
نیوٹن کی نظر میں کائنات اور فطرت ایک بے جان مشین تھی، اور انسان ایک انجینئر کی طرح تھا۔ کائنات کے اس نظریے کو ’’میکانیکیت‘‘ کہتے ہیں۔ انیسویں صدی میں بعض مفکروں نے اس نظریے کو رد کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ کائنات اور فطرت بھی انسان کی طرح جان رکھتی ہے اور نمو اس کی بنیادی خصوصیت ہے اور کائنات خود اپنی توانائی سے زندہ ہے۔ اس نظریے کو ’’نامیت‘‘ کہتے ہیں۔ یہ ایک اور جھگڑا ہے جو تقریباً دو سو سال کے عرصے میں مغرب کے فلسفی اور سائنس داں دو حریف جماعتوں میں صف آرا چلے آ رہے ہیں۔ ایک گروہ میکانیکیت کا قائل ہے، دوسرا نامیت کا۔
علم نفسیات کا آغاز:
عقلیت پرستی کے دور میں ہی نفسیات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے نفسیات کوئی الگ علم نہیں تھا، بلکہ فلسفے ہی کا حصہ تھا۔ ابن رشد نے تو علم النفس کو طبیعیات کے ماتحت رکھا ہے۔ نفسیات کو فلسفے سے الگ کرنے کا کام سترہویں صدی کے دوسرے حصے میں انگریز مفکر لاک (Locke) نے سر انجام دیا اور اس کے نظریات میں اضافہ اٹھارہویں صدی کے انگریز مفکر ہارٹلے (Hartley) نے کیا۔ نیوٹن نے کائنات کو مشین سمجھا تھا۔ ان دو مفکروں نے انسانی ذہن کو بھی مشین سمجھا۔ ان کا خیال ہے کہ ذہن بجائے خود کوئی چیز نہیں۔ خارجی اشیاء انسان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں <مثلاً کوئی چیز دیکھی یا سونگھی یا چھوئی>undefined تو اعصاب میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش دماغ کے مرکز میں پہنچ کر تصویر کی شکل میں تبدیل ہوجاتا ہے اور پھر تصویر خیال بن جاتی ہے۔ اس طرح خارجی اشیاء کے عمل سے ذہن پیدا ہوتا ہے۔
پادری بارکلے کی لادینیت: نظریہ مثالیت
اس نظریے کا جواب اٹھارہویں صدی میں پادری بارکلے (Berkeley) نے دیا۔ اس کا خیال ہے کہ خارجی اشیاء کو وجود حاصل نہیں، بلکہ ذہن خارجی اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے پھول دیکھا، تو اس کے پاس پھول کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ تو بس ایک ذہنی ادراک ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ ذہن خارجی اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ پادری بارکلے نے انسانی ذہن کے نمونے پر خدا کا بھی ذہنی تصور کیا تھا <نعوذ باللہ>undefined۔ اس نظریے کو ’’مثالیت‘‘ (Idealism) کہتے ہیں۔
انسانی ذہن کے یہ دونوں نظریے دراصل روح اور مادے کے اسی تقابل کا نتیجہ ہیں جو دیکارت سے شروع ہوا تھا اور اسی لیے ان دونوں کے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہوسکتی۔
ہیوم کا فلسفۂ شک:
اٹھارہویں صدی کا انگریز فلسفی ہیوم (Hume) ایک معاملے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر ایسے لفظ کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرتا ہو جسے حسی تجربے میں نہ لایا جاسکے یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ انسانی زبان و بیان سے ایسے لفظ بھی خارج کر دیئے جائیں جن کا تعلق روحانیت سے ہو۔ یہ رجحان آگے چل کر انیسویں صدی میں فرانس کے فلسفی کونت (Comte) کے نظریۂ ’’ثبوتیت‘‘ (Positivism) کی شکل میں ظاہر ہوا اور بیسویں صدی میں انگریزوں کے ’’منطقی ثبوتیت‘‘ (Logical Positivism) کی شکل میں۔ ان فلسفوں کا بیان آگے ہوگا۔
خدا شناسی: دہریت کی قسم
اٹھارہویں صدی میں ایک نئی قسم کا مذہب نمودار ہوا جو دراصل دہریت کی ایک شکل ہے۔ اس کا نام Deism <خدا شناسی>undefined رکھا گیا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ عقل <جزوی>undefined انسان کا خاص جوہر ہے، اور یہ چیز ہر زمانے اور ہر جگہ کے انسانوں میں مشترک ہے اور ہر جگہ ایک ہی طرح کام کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کو پہچاننے کے لیے وحی پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں، عقل <جزوی>undefined کی مدد سے بھی خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ عقل کے ذریعے چند ایسے اصول معلوم کیے جاسکتے ہیں جو سارے مذاہب میں مشترک ہوں۔ ان اصولوں کا مجموعہ ہی اصل مذہب ہوگا۔
برعظیم پاک و ہند میں خدا شناسی کے میلے:
جب انگریز ہمارے یہاں آئے تو ان کے اثر سے یہ رجحان ہمارے برصغیر میں بھی پہنچا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کے بعد ’’خدا شناسی‘‘ کے جو میلے انگریزوں نے کرائے ان کے پیچھے یہی رجحان تھا۔ ہندو اس سے بہت متاثر ہوئے اور انیسویں صدی کے شروع میں راجا رام موہن رائے نے جو ’’برہمو سماج‘‘ کی بنیاد ڈالی وہ اسی اثر کا نتیجہ تھا۔ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ۱۸۳۶ء میں کمبل پوش نے یورپ کا سفر کیا تھا اور دس سال بعد اپنا سفر نامہ لکھا۔ ان کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ہی وہ ’’خدا شناسی‘‘ سے متاثر ہوچکے تھے۔ اس کا نام انھوں نے ’’سلیمانی مذہب‘‘ رکھا ہے۔ اسی کے اثرات اردو شاعر غالبؔ کے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔
جدیدیت میں معاشرے اور پھر فرد کی اہمیت:
عقلیت پرستی کے دور کی ایک مرکزی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے انسانی زندگی اور انسانی فکر میں سب سے اونچی جگہ معاشرے کو دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ فرد کو اپنے ہر فعل اور قول میں معاشرے کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ لوگ مذہب کو بھی صرف اسی حد تک قبول کرتے تھے جس حد تک کہ مذہب معاشرے کے انضباط میں معاون ہوسکتا ہے۔ غرض معاشرے کو بالکل خدا کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ نعوذ باللہ۔ اس کے خلاف ردعمل انیسویں صدی میں ہوا اور معاشرے کے بجائے فرد کو اہمیت دی گئی۔ بیسویں صدی میں اشتراکیت کے زیرِ اثر بعض لوگ معاشرے کو پھر خدا ماننے لگے۔
مغربی فکر و فلسفہ: وحدت افکار سے خالی
مغربی فکر میں جس طرح روح اور مادے، ذہن اور جسم، عقل اور جذبے کے درمیان مسلسل کشمکش جاری ہے، اسی طرح معاشرے اور فرد کی کشمکش بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا بھی کوئی حل نہیں ملتا۔ مغرب میں جو معاشرتی انتشار پھیلا ہوا ہے اور روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے اس کی جڑ یہی تضاد ہے۔
مادے میں وحدت تلاش نہیں کی جاسکتی:
ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا ذہن کسی طرح کی وحدت تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور دوئی، تضاد اور کثرت میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ وحدت کا اصول قائم کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوسکیں۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ مغرب مادے میں وحدت ڈھونڈتا ہے جہاں کثرت اور شکست و ریخت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔
مغرب چاہے معاشرے کو اوپر رکھے یا فرد کو، دونوں نظریوں میں ایک بات مشترک ہے۔ انسان پرستی، بیسویں صدی میں بعض مفکر اور ادیب ایسے بھی ہیں جو انسان کو حقیر سمجھتے ہیں یا انسان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی فکر کا مرکز بھی انسان ہی ہے۔
انقلابِ فرانس:
اس واقعے کو امتیازی جگہ دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس نے یورپ کی تاریخ اور فکر پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے اور اس سے مشرقی ممالک بھی شدید طور سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تو ۱۷۹۰ء کے قریب ہوا تھا اور بادشاہ کو قتل کر کے جمہوری حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ لیکن اصل اہمیت ان اصولوں کی ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہے تھے۔
انقلاب فرانس: آزادی اخوت مساوات
انقلاب فرانس کا نعرہ تھا۔ آزادی، اخوت، مساوات۔ اس انقلاب کو جمہوریت کی فتح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مغرب کا تصورِ جمہوریت واضح طور سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں انگریزی تعلیم پانے والوں نے یہ بات تسلیم کرلی ہے کہ اسلام بھی اخوت اور مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لفظ مساوات سے بعض دفعہ ہمارے علماء بھی دھوکا کھا جاتے ہیں لیکن ایسے الفاظ کا مطلب مغرب میں بالکل ہی دوسرا ہے۔ لہٰذا مغربی جمہوریت بھی اسلام سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔
انقلابِ فرانس کے وقت تو بظاہر آزادی اور مساوات کا مطلب یہی تھا کہ عوام پر جبر نہیں ہونا چاہیے اور قانون کی نظر میں سب کا درجہ مساوی ہونا چاہیے۔ مگر ان الفاظ میں جو مفہوم پنہاں تھا وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔
شیخ سعدیؒ نے کہا ہے بنی آدم اعضائے یک دیگراند۔ اس سے ان کی مراد روحانی رشتہ ہے۔ اسلامی اخوت کے یہی معنی ہیں مگر مغرب والوں کی نظر میں صرف اتنی بات ہے کہ سارے انسانوں کی جسمانی اور نفسانی ضروریات ایک سی ہیں۔ مغرب والے اس بناء پر اخوت کے قائل ہیں۔
مساوات کے معنی بھی وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ صرف جسمانی ضروریات یا معاشرتی ضروریات اور انھیں پورا کرنے کے حقوق کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے سارے انسان مساوی ہیں۔ لہٰذا انسانوں کے درمیان درجہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ذہنی استعداد کے لحاظ سے انسانوں میں جو لازمی فرق ہوتا ہے اسے بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اسی اصول کی بنا پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں بھی سب کا درجہ مساوی ہونا چاہیے اور دین کو سمجھنے کا حق بھی سب کو مساوی طور پر ملنا چاہیے۔
ظاہر ہے کہ مساوات کا یہ تصور انسانی فطرت کے حقائق کے بالکل خلاف ہے، اور اس پر کبھی عمل نہیں ہوسکتا۔ مگر مغرب والے اپنا ’’جمہوری‘‘ اصول اور اپنا ’’مساوات‘‘ کا تصور بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کا عملی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ صرف ’’انسان‘‘ کو بلکہ ’’عام آدمی‘‘ کو ہر چیز کا آخری معیار بنا لیا گیا ہے۔ شعر و ادب ہو یا فلسفہ یا مذہب، آج کل بیسویں صدی میں ہر جگہ یہی مطالبہ ہے کہ جو بات ہو ’’عام آدمی‘‘ کی سمجھ کے مطابق ہو اور اس کی جسمانی اور ذہنی ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ چونکہ ’’عام آدمی‘‘ اپنی سطح سے اوپر اٹھنے کی استعداد نہیں رکھتا، اس لیے دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ سب کے سب نیچے اتر کے ’’عام آدمی‘‘ کی سطح پر آجائیں اور جو چیز ’’عام آدمی‘‘ کی سمجھ میں نہ آئے وہ گردن زدنی ہے۔ اصرار اس بات پر ہے کہ جس طرح معاشرتی دائرے میں کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھا جانا چاہیے اسی طرح ذہنی دائرے میں بھی بہتر یا کہتر کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے بیسویں صدی کو ’’عام آدمی کی صدی‘‘ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔
بیسویں صدی: عام سمجھ بوجھ کی پرستش کی صدی
’’عام آدمی‘‘ کی پرستش کے ساتھ ساتھ ’’عام سمجھ بوجھ‘‘ (Comon Sense) کی بھی پرستش ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چیز ’’عام سمجھ بوجھ‘‘ کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو وہ غلط ہے یا توجہ کے لائق نہیں۔ اس لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ’’عام سمجھ بوجھ‘‘ کے دائرے سے باہر ہوں انھیں یا تو ختم کر دیا جائے یا کانٹ چھانٹ کر ’’عام سمجھ بوجھ‘‘ کے دائرے میں لے آیا جائے۔ ہمارے یہاں جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، یا عام آدمی کو بھی اسلام کے سمجھنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا علماء کو، تو اس کے پیچھے یہی ذہنیت کار فرما ہے۔
علماء جمہوریت اور مساوات کی اصطلاحات پر تدبر کریں:
غرض، جمہوریت اور مساوات کے اصولوں کو سیاست، معیشت اور قانون کے دائرے میں محصور نہیں رکھا گیا، بلکہ ان دائروں میں بھی عائد کیا گیا ہے جہاں ان کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔
چنانچہ علماء کو ان دو لفظوں یعنی ’’جمہوریت‘‘ اور ’’مساوات‘‘ کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔
’’انقلاب فرانس‘‘ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے دو متضاد رجحانات کار فرما رہے ہیں ایک تو عقلیت پرستی جس کا نمائندہ والنیئر ہے اور دوسرا جذبات پرستی اور فطرت پرستی جس کا نمائندہ روسو ہے۔ <یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روسو نے اپنے اصول اسلام سے اخذ کیے تھے>undefined
٭6۔انیسویں صدی – نظریاتی تبدیلی کا دور
اس زمانے سے دنیا پر مغرب کا سیاسی اور مادی غلبہ شروع ہوتا ہے۔ اس صدی کے آخر تک سیاسی طور سے یا کم سے کم معاشی طور سے ساری دنیا پر مغرب کی شہنشاہیت قائم ہوگئی تھی۔ یہی دور سائنس کی ترقی اور ریل، تار برقی وغیرہ ایجادات کا ہے جن کی مدد سے مغرب نے دنیا کو فتح کیا اور ذہنی طور سے بھی مرعوب کیا۔
خود مغرب میں یہ دور ’’صنعتی انقلاب‘‘ کا ہے یعنی مغرب میں معیشت کا انحصار زراعت پر نہیں رہا بلکہ صنعت اور کارخانہ داری پر ہوگیا۔ انیسویں صدی میں سرمایہ دارانہ نظام پوری طرح جم گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے شروع ہوئے اور سرمایہ داری کے ردعمل کے طور پر نصف صدی کے بعد اشتراکیت کی تحریک شروع ہوئی۔
انیسویں صدی میں معاشرے کے متعلق تین خاص نظریات رائج ہوئے:
۱۔ انفرادیت پسندی (Individualism):
اس کا سب سے بڑا نمائندہ انگریز مفکر جان اسٹورٹ مل ہے۔ اس نظریے کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ معاشرہ خدا کی تخلیق نہیں ، بلکہ انسان نے اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے معاشرہ بس افراد کا مجموعہ ہے۔ فرد معاشرے کے لیے نہیں بلکہ معاشرہ فرد کے لیے ہے چنانچہ فرد کو اپنی زندگی میں پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے اور معاشرے یا حکومت کا دخل کم سے کم ہونا چاہیے چونکہ اس زمانے میں سرمایہ داروں کو معاشی معاملات میں خود مختاری اور آزادی کی ضرورت تھی، اس لیے انیسویں صدی میں غلبہ اسی نظریے کو حاصل رہا۔
۲۔ مثالیت (Idealism):
یہ فلسفہ اٹھارہویں صدی کے دوسرے حصے میں جرمن فلسفیوں نے شروع کیا۔ اس کا سب سے بڑا نمائندہ ہیگل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل چیز معاشرہ ہے اور فرد اس کا جزو ہے۔ یہ فلسفی فرد کو معاشرے کا ایسا تابع کرتے ہیں کہ فرد کے حقوق باقی ہی نہیں رہتے، بلکہ فرد کا الگ وجود بھی نہیں رہتا۔ اس فلسفہ کا اثر انیسویں صدی میں تو محدود ہی رہا۔ لیکن بیسویں صدی میں پہلی جنگِ عظیم کے بعد اس فلسفے نے ہٹلر اور مسولینی کی آمریت پیدا کی۔
۳۔ نامیت (Organism):
ہیگل وغیرہ نے تو محض تشبیہہ کے طور پر معاشرے کو جسم کہا تھا۔ لیکن سائنس کے زیرِ اثر چند ایسے مفکر پیدا ہوئے جو معاشرے کو لفظا و معناً جسم ہی کہتے ہیں۔ مثلاً انگریز مفکر ہر برٹ اسپنسر۔ ان لوگوں کے نزدیک معاشرہ بھی جاندار اجسام کی طرح ہے اور اس پر بھی حیاتیات کے اصول عائد ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معاشرے کو نہ تو مذہبی اقدار کی ضرورت ہے نہ اخلاقی اقدار کی، فطری عوامل اور فطری قوانین جو کچھ کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اسپنسر نے تو معاشرہ پر حیاتیات کا قانون ’’بقائے اصلح‘‘ بھی عائد کیا۔ یعنی جو شخص یا معاشرہ مادی ترقی کر رہا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے اور جو ترقی نہیں کر رہا اسے ’’جہنم میں ڈالو‘‘ اس کے اصولوں کا خلاصہ اس ایک مشہور فقرے میں آجاتا ہے۔
“Each one for himself, and the Devil take the hindmost”.
<’’ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے، اور جو پیچھے رہ جائے وہ جہنم میں جائے‘‘۔>undefined
حواس و ادراک سے ماورا شے حقیقت نہیں ہوسکتی: کومٹ کا فلسفہ
نظریات کے اختلافات جو بھی ہوں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں انسانی اور معاشرتی نقطۂ نظر سے غور کرنا مغربی ذہن کی عادت ثانیہ بن گیا۔ انیسویں صدی میں ہی فرانسیسی مفکر کونت (Comte) نے عمرانیات (Sociology) کے علم کی بنیاد رکھی۔ یہی شخص ایک نئے فلسفہ ’’ثبوتیت‘‘ (Positivism) کا بھی بانی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز حواس اور حسیات کے ذریعے ادراک میں آسکے صرف وہی حقیقت ہے، اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ رجحان تو پہلے بھی موجود تھا، کونت نے اسے ایک باقاعدہ فلسفے کی شکل دے دی۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ وحی، روح، خدا سب سے منکر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انسانی ذہن ’’ارتقا‘‘ کے عمل سے گزرتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جادو کا دور تھا، پھر مذہب کا دور آیا، پھر فلسفے کا اور اب سائنس اور عقل <جزوی>undefined کا دور شروع ہوا ہے۔ اس نقشے کے مطابق مذہب انسانی ذہن کے ضعف اور ناپختگی کی علامت ہے۔
٭انیسویں صدی: بنیادی تبدیلیاں
- مذہب کی جگہ سیاست نے لے لی
- چونکہ معاشرتی اور معاشی انتشار کا آغاز ہوگیا تھا، اس لیے انیسویں صدی سے سیاست اہم ترین چیز بن گئی اور بیسویں صدی میں تو بعض لوگوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے زمانے کے لیے سیاست کی وہی اہمیت اور وہی جگہ ہے جو پہلے مذہب کی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ انیسویں صدی سے مغربی فکر کا مرکز اور سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ بن گیا کہ معاشرے کی تنظیم کیسے کی جائے۔ یہاں تک کہ مذہب کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ مذہب کسی معاشرتی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں اور مذہب انسانی معاشرے کے لیے لازمی ہے یا نہیں۔
- مذہب کو حق و باطل کی میزان نہ ٹھہرایا جائے: مذہب کھیل تماشہ
- کونت کے اثر سے انیسویں صدی ہی میں یہ رجحان پیدا ہوگیا اور بیسویں صدی میں تو بالکل غالب آگیا کہ مذہب کے معاملے میں حق و باطل کا سوال نہ اٹھایا جائے بلکہ عقائد اور مذہبی رسوم کو عمرانی عوامل اور مظاہر میں شمار کیا جائے اور مذہب کا مطالعہ بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح دوسرے عمرانی مظاہر کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر عقیدے اور ہر مذہبی چیز کی تشریح عمرانی نقطۂ نظر سے کی گئی۔ یہ انداز بیسویں صدی میں عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اس قسم کے مفکر مذہب کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات مذہب کی تحسین کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر میں مذہب کی وہی قدر و قیمت ہے جو کھیل تماشوں کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ لوگ کھیل تماشوں کو چھوٹی چیز نہیں سمجھتے بلکہ انھیں انسان کی بلند ترین اور دقیع ترین سرگرمیوں میں شمار کرتے ہیں۔
- تاریخ پرستی کا فلسفہ:
- انیسویں صدی میں عمرانی نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ تاریخی نقطۂ نظر بھی وجود میں آیا اور بہت مقبول ہوا۔ اس اندازِ نظر کو ’’تاریخ پرستی‘‘ (Historicism) کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مذہبی عقیدہ اور اصول ہو یا فلسفیانہ خیال یا کوئی اور چیز، اس کے صحیح یا غلط ہونے پر غور نہ کیا جائے بلکہ اس کی تاریخ پر تحقیق کی جائے اور یہ دیکھا جائے کس زمانے میں اس کی نوعیت اور حیثیت کیا رہی ہے۔ مذہب سے لوگوں کو برگشتہ کرنے میں اور مذہب سے بے اعتنائی پیدا کرنے میں یہ حربہ بہت کار گر رہا ہے۔ اسلام کے خلاف مستشرقین جو کچھ کرتے رہے ہیں اس میں ان کا طریقہ کار عموماً یہی رہا ہے۔
- ’’تاریخ پرستی‘‘ کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے اثر سے اور خصوصاً ایجادات سے مرعوب ہو کر مغربی ذہن اور مشرق کے جدید لوگوں کا ذہن محض ’’واقعات‘‘ (Facts) کو دلیل اور ثبوت سمجھنے لگا ہے اور یہ حقیقت بھول گیا ہے کہ ایک ہی ’’واقعے‘‘ سے متضاد قسم کے نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ کسی ’’واقعے‘‘ کو مثال کے طور پر تو ضرور پیش کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جاسکتی۔ بہرحال جدید مغربی ذہن ’’واقعات‘‘ ہی پر پورا بھروسہ کرتا ہے۔
- مذاہب کے تقابلی مطالعے کا علم:
- تاریخ پرستی اور عمرانیات کے ساتھ ہی ساتھ ایک نیا علم شروع ہوا جسے مذاہب کا تقابلی مطالعہ‘‘ کہتے ہیں۔ اس علم کا مقصد کسی قسم کے حق یا صداقت تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا کہ مختلف مذاہب کن کن باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا الگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر اور بے مقصد کام معلوم ہوتا ہے لیکن مذہب سے بے اعتنائی پیدا کرنے میں اس علم کا بہت بڑا داخل ہے۔
- فطرت پرستی کی گمراہ تحریک:
- یہی وہ دور ہے جب مادیت مغرب کے ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے۔ انیسویں صدی میں تقریباً یہ بات طے ہوگئی کہ حسی اور مادی کائنات سے آگے کوئی حقیقت نہیں۔ اس ضمن میں کونت کی ’’ثبوتیت‘‘ کا ذکر ہوچکا ہے۔ اسی مادیت کے رجحان کا دوسرا نام ’’فطرت پرستی‘‘ (Naturalism) ہے۔ فلسفہ میں تو اس نظریے کے معنی یہ ہیں کہ ’’فطرت‘‘ <یعنی مادی اور حسی کائنات>undefined کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ مگر انیسویں صدی کے مغربی شعر و ادب میں ایک خاص قسم کی فطرت پرستی رائج ہوئی۔ یہاں ’’فطرت‘‘ سے مراد میدان، پہاڑ، دریا، پھول، چڑیاں وغیرہ ہیں۔ انیسویں صدی میں ان چیزوں کے بارے میں ہزاروں نظمیں لکھی گئیں۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں معلوم ہوتی۔ مگر عموماً ایسے شاعروں کا عقیدہ یہ تھا کہ فطرت جاندار ہے اور خود اپنی توانائی سے زندہ ہے اور حقیقتِ عظمیٰ بھی فطرت کی مختلف اشکال کے اندر رہتی ہے۔ بعض لوگ تو صاف طور سے ’’خدا‘‘ کا نام لیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نعوذ باللہ ’’احاطہ‘‘ کے قائل تھے۔ <سرسید نے جو ’’نیچری‘‘ تحریک شروع کی اور حالی وغیرہ نے جو ’’نیچرل شاعری‘‘ کا نعرہ لگایا اس کا پس منظر یہ ہے۔ مگر ان بے چاروں کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں>undefined۔
- افادیت پرستی کی گمراہی:
- انیسویں صدی میں اخلاقیات کا ایک نیا نظریہ مقبول ہوا۔ اسے ’’افادیت پرستی‘‘ (Utilitarianism) کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کوئی چیز بذاتِ خود نہ تو اچھی ہے نہ بری۔ اچھائی اور برائی کا معیار ’’فائدہ‘‘ ہے۔ جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے <یعنی مادی اور عملی زندگی میں>undefined وہ اچھی ہے اور جو چیز فائدہ مند نہیں وہ بری ہے۔ <ہمارے یہاں اس تحریک کے اثر کی بین مثال یہ ہے کہ شبلی مرحوم کے ایک دوست نے اپنا نام تک مہدی الافادی الاقتصادی رکھ لیا تھا>undefined۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی نظام نہیں بلکہ اخلاقیات کا رد ہے۔
- اخلاقیات کی بنیاد: وحی نہیں عقل ہے: آزاد اخلاقیات کا فلسفہ
- اس دور کے بعض مفکروں نے اخلاقیات کا ایک اور نظریہ پیش کیا۔ دنیا کے ہر معاشرے میں اخلاقیات کا انحصار مذہب پر رہا ہے اور اخلاقیات کو مذہب کا ایک شعبہ سمجھا گیا ہے۔ یہی حال یورپ میں بھی تھا۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں یہ کوشش ہوئی کہ اخلاقیات کی بنیاد وحی پر نہیں، بلکہ انسانی عقل پر رکھی جائے۔ انیسویں صدی کے بعض مفکروں نے یہ حرکت کی کہ زیادہ تر اخلاقی اصول تو وہی رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے مگر اخلاقیات کو مذہب سے الگ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو نیک کام خدا یا جہنم کے ڈر سے کئے جائیں وہ نیکی میں شمار ہونے کے لائق نہیں۔ اصلی نیکی تو وہ ہے جو ’’دل‘‘ سے نکلے۔ چنانچہ انھوں نے اخلاقی اقدار کو خدا کے احکام کہنا چھوڑ دیا اور اخلاقیات کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کی فطرت معصوم اور پاکیزہ ہے اور وہ خود بہترین اخلاقی اصول پیدا کرتی ہے۔ <انسانی فطرت کے معصوم اور پاکیزہ ہونے کا خیال فرانسیسی مفکر روسو سے شروع ہوا>undefined چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا ’’دل‘‘ سے برآمد ہونے چاہئیں۔ اس نظریے کا نام ’’آزاد اخلاقیات‘‘ (Liberal Ethics) ہے۔
- مذہب کو صر ف اخلاقی نظام قرار دینا: آزاد دینیات
- اسی طرح بعض لوگوں نے ایک ’’آزاد دینیات‘‘ ایجاد کی جس کا دارو مدار انسان کی ’’معصوم فطرت‘‘ پر تھا۔ یہ بات تاکید کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ انیسویں صدی میں مغربی ذہن پر خصوصاً پروٹسٹنٹ ملکوں میں اخلاقیات بری طرح حاوی تھی۔ یہ لوگ اخلاقیات کو مذہب کا سب سے لازمی جز سمجھتے تھے۔ بلکہ بعض لوگ تو مذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام سمجھتے تھے، یا مذہب کو اخلاقیات کا ایک شعبہ۔ اس رجحان کا اثر سرسید وغیرہ پر بہت گہرا پڑا ہے اور آج تک چلا آرہا ہے۔ چنانچہ جب انگریزی تعلیم یافتہ لوگ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی تعریف کریں تو ہمارے علماء کو ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ تو تصوف کو بھی بس اخلاقیات ہی خیال کرتے ہیں۔
- انیسویں صدی میں ایک طرف تو عقل پرستی بڑھتی جا رہی تھی دوسری طرف جذبات پرستی کی بھی شدت تھی۔ بعض لوگ حق و باطل، خیر و شر کے درمیان اسی طرح امتیاز کرتے تھے کہ جذبات کے لیے کون سی چیز تسلی بخش ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ مذہب کو بھی جذبات کی تسکین اور تسلی کا ایک ذریعہ تصور کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غرض عقل پرستی ہو یا جذبات پرستی ہے وہی نفس پرستی۔
- نئی گمراہی عقائد کو Dogmas کہنا:
- انیسویں صدی کے بعض لوگ مذہب کو بالکل رد کرتے تھے، بعض اسے اخلاقی اور معاشرتی نظام کے طور پر قبول کرتے تھے، اور بعض یہ کہتے تھے کہ مذہبی عقائد ہیں تو غیر عقلی اور بے معنی مگر ’’جذباتی تسکین کے لیے لازمی ہے۔ بہرحال مذہبی عقائد کے سب لوگ خلاف تھے۔ رومن کیتھلک لوگ اپنے عقائد کو Dogmas کہتے ہیں جن کا تعین پوپ کرتا ہے۔ اس لفظ کو لوگ خصوصاً پروٹسٹنٹ لوگ، تحقیر اور نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کرنے لگے۔ آج کل ہمارے یہاں کے تجدد پسند بھی اسلامی عقائد کو حقارت کے ساتھ Dogmas کہتے ہیں اور انھیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
- عبادت کا نام رسوم و رواج رکھنا:
- عقائد کے علاوہ عبادات سے بھی انیسویں صدی کے لوگ عموماً خفا تھے۔ اور انھیں غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ان کا نام ’’رسوم‘‘ یا ’’رسوم و رواج‘‘ رکھا گیا تھا۔ یہاں بھی پروٹسٹنٹ ذہنیت کام کر رہی تھی جن نے رومن کیتھلک عبادات کو ترک کر دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ خدا کی عبادت کے لیے خاص اور مقررہ شکلوں کی ضرورت نہیں، بس خلوص کافی ہے۔ اسی خلوص کو یہ لوگ اصلی مذہب سمجھتے تھے _ یعنی جذبات کو۔ اس طرح انیسویں صدی میں مذہب کے بجائے ایک ’’جعلی مذہبیت‘‘ رائج ہوگئی تھی۔ عبادات کو ’’غیر ضروری رسوم‘‘ کہنے کا رواج اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا ہے۔
- آزاد خیالی: مذہب کی مخالفت کا سنہری نام
- انیسویں صدی میں ایک اور اصطلاح بہت مقبول ہوئی __ ’’آزاد خیالی‘‘ (Free-Thought) اس کا مطلب ہے مذہب کی کھلم کھلا مخالفت کرنا، یا مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔
- انیسویں صدی میں جس چیز نے ایسی ’’آزاد خیالی‘‘ اور تشکیک کو سب سے زیادہ تقویت پہنچائی وہ انگریز سائنس دان ڈارون کا نظریۂ ارتقا تھا۔ اس نظریے کا کوئی حتمی ثبوت ڈارون کو نہیں مل سکا تھا اور نہ ابھی تک ملا ہے۔ بلکہ آج کل تو اس نظریے کی خاصی مخالفت بعض سائنس دانوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ خالی نظریہ ہی نظریہ تھا۔ بہرحال یہ نظریہ مذہبی عقیدے کی طرح جڑ پکڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو کائنات ایک دم سے وجود میں آئی ہے نہ انسان، بلکہ کائنات کی ہر چیز اور انسان اپنی موجودہ ہیئت تک لاکھوں سال کی تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد پہنچا ہے اور مسلسل تبدیلی کا قانونی فطرت کے بنیادی عوامل میں سے ہے۔
- کائنات کی تخلیق: کن فیکون سے نہیں ہوئی
- یہ نظریہ اس عیسوی عقیدے کی تردید کرتا تھا کہ خدا نے کائنات کو ایک لفظ کہہ کر تخلیق کیا ہے۔ اس تضاد نے لوگوں کے دل میں مذہب کی طرف سے شدید شک اور بدگمانی پیدا کر دی ہے۔ سائنس کے ہاتھوں عیسائیت کو جو زک اٹھانی پڑی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو مکمل تنزیہہ اور توحید حاصل نہیں تھی۔ تثلیت کے عقیدے نے انھیں تشبیہہ میں بری طرح الجھا دیا تھا۔ پھر یونانیوں کے زمانے سے ہی مغرب نے کائنات پر زیادہ توجہ صرف کی تھی، اور کسی نہ کسی قسم کا نظریۂ کائنات ہمیشہ مذہب کا لازمی جز، بلکہ غالب جز رہا تھا۔ اس لیے سائنس نے کائنات یا فطرت کے بارے میں جب کبھی کوئی نئی بات کہی، مغرب کے مذہب کو صدمہ پہنچا۔ اسلام کا انحصار چونکہ کسی نظریۂ کائنات پر نہیں اس لیے سائنس کا کوئی نظریہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوسکتا۔
- لفظ ارتقاء: اخلاقی کے بجائے مادی نظریہ بن گیا
- نظریۂ ارتقا نے عیسائیوں کے ایمان کو تو کمزور کر دیا، لیکن ایک دوسری قسم کا نیم مذہبی عقیدہ بھی ساتھ ساتھ پیدا کر دیا۔ ڈارون نے اپنے نظریے کا نام ’’ارتقا‘‘ رکھا یہ دراصل غلط نام ہے۔ کیونکہ ڈارون نے تو صرف یہ دکھایا تھا کہ فطرت کی اوضاع میں اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خالص سائنس کے نقطۂ نظر سے یہاں اچھے اور برے، بہتر اور کمتر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف لفظ ’’ارتقا‘‘ ایک اخلاقی مفہوم رکھتا ہے اور اس کے معنی <معنی نہیں تاثر>undefined ہوتے ہیں ’’پہلے سے بہتر ہوتے جانا‘‘۔ چنانچہ ڈارون کا نظریہ غلط ہو یا صحیح یہ لفظ جادو کا سا کام کر گیا اور اپنے اخلاقیاتی یا فلسفیانہ مفہوم کی بنا پر یہ نظریہ فوراً مقبول اور ہر دلعزیز ہوگیا۔ انیسویں صدی میں صنعت اور سائنس نے نئی نئی ترقی کی تھی جس سے لوگ خوش تھے اور جس پر فخر کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے ڈارون کے نظریے سے یہ غیر منطقی نتیجہ نکالا کہ فطرت کے قوانین نے ہزاروں قسم کے جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاک کر دیا، بس انسان ایک ایسا جاندار ہے جو برابر ترقی کرتا چلا آرہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسان پر بہت مہربان ہے اور یہ مہربانی آئندہ بھی جاری رہے گی۔ پھر یہ ترقی صرف مادی ہی نہیں، بلکہ اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی بھی ہوگی۔ غرض انسان ہمیشہ سے ہر معنی میں ترقی کرتا چلا آرہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح ترقی کرتا رہے گا۔ اس لیے انسان کا فرض ہے کہ اپنی تمام طاقتیں ترقی کے کام میں لگا دے۔
- پروگریس کا تصور نظریہ ارتقاء کا فطری نتیجہ:
- یہ ’’ترقی‘‘ (Progress) کا تصور انیسویں صدی میں شروع ہوا اور دو عالمگیر جنگوں کے بعد بھی اس کا جادو ختم نہیں ہوا۔ بیسویں صدی میں اس تصور کا مذاق بھی بہت اڑایا گیا ہے، لیکن اس کا اثر کم ہونے میں نہیں آتا۔ بلکہ اب تو مغرب سے زیادہ مشرقی ممالک اس سے مسحور ہو رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے انیسویں صدی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے عروج کا زمانہ ہے۔ اسی دور میں ’’عام آدمی‘‘ نے اپنی اہمیت جتانی شروع کی اور یہ مطالبہ ہونے لگا کہ ہر معاملے میں عام آدمی کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے۔
- افادیت پرستی: شعر و ادب بے کار ٹھہرے
- انیسویں صدی میں افادیت پرستی اس حد تک پھیل گئی تھی کہ لوگوں نے شعر و ادب وغیرہ تہذیبی سرگرمیوں کو بے کار کہنا شروع کر دیا۔ اب تک ہر تعلیم یافتہ آدمی کے لیے شعر و ادب کا ذوق رکھنا ضروری خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب بے ذوقی عام ہونے لگی۔ <اسی رجحان کے زیرِ اثر ہمارے یہاں سرسید کے ساتھیوں نے شعر و شاعری کو قوم کے لیے مہلک بتایا>undefined اس بے ذوقی اور بے اعتنائی کا ردعمل ایک اقلیت پر یہ ہوا کہ وہ شعر و ادب اور ثقافت کو انسانی زندگی کا ماحصل سمجھنے لگی۔ بعض مفکروں نے تو شعر و ادب کو مذہب کی جگہ رکھنا چاہا۔ بیسویں صدی میں یہ دونوں رجحان اور بھی شدت اختیار کر گئے۔ ایک طرف مغرب میں لوگوں کی غالب اکثریت شعر و ادب سے بالکل بیگانہ ہوگئی۔ دوسری طرف چند لوگوں نے شعر و ادب اور ثقافت کو آسمان پر چڑھا دیا، بلکہ یہ سمجھا جانے لگا کہ مذہب بھی ثقافت ہی کا جز ہے اور اسی حیثیت سے قابلِ قدر ہے۔
- مغربی روحانیت: روحوں سے باتیں کرنا
- انیسویں صدی ہی میں ’’روحانیت‘‘ کے لفظ کو ایک اور معنی بھی حاصل ہوئے۔ یعنی روحوں سے باتیں کرنا، مستقبل کا حال بتانا اور اسی قبیل کی چیزیں یہ حرکتیں یوں تو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں جاری رہی ہیں، لیکن ان کو کبھی وقعت نہیں دی گئی۔ لیکن انیسویں صدی میں یورپ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد انھیں چیزوں کو اصلی روحانیت اور مذہب کا ماحصل سمجھنے لگی۔ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے انھوں نے اپنی روحانیت‘‘ کو بیک وقت مذہب بھی بتایا اور سائنس بھی۔ بیسویں صدی میں یہ رجحانات اتنے پھیل گئے ہیں کہ ان کی وسعت اور طاقت کا اندازہ مشکل ہے۔ پھر بعض سائنس دانوں نے ’’ماورائے حس ادراک‘‘
undefined پر تجربے کر کے ان حرکتوں کو ’’سائنس‘‘ کی حیثیت سے بھی وقعت دے دی ہے۔ اس طرح عقلیت کی تحریک بدترین قسم کی ضعیف الاعتقادی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ’’روحانیت‘‘ کسی نہ کسی شکل میں انیسویں صدی کے آخری حصے سے ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے۔ - مستشرقین کی تحریک:
- انیسویں صدی نے ہی مستشرقین کی تحریک پیدا کی ہے۔ مشرقی علوم اور ادیان کے بارے میں مغربی لوگ پہلے بھی لکھتے رہے ہیں، خصوصاً اٹھارہویں صدی میں ہندوؤں اور چینیوں کے علوم کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے، لیکن مستشرقین کے کام نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل انیسویں صدی میں اختیار کی۔ اس کام کی ایک تو سیاسی ضرورت تھی، کیونکہ مغرب نے مشرقی ممالک میں اپنی شہنشاہیت قائم کرلی تھی، لہٰذا مفتوحہ قوموں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آرہی تھی۔ دوسرے عیسائی مشنریوں کو اپنا کام کرنے کی پوری آزادی اور حکومتوں کی حمایت حاصل ہوگئی تھی۔ انھوں نے بھی اپنے مقاصد کے تحت مشرقی علوم کے مطالعے کی طرف توجہ کی۔ مگر ان دو مقاصد کے علاوہ مستشرقین کے پیچھے بہت سے وہ رجحانات کام کر رہے تھے جو اوپر گنوائے گئے مثلاً مذاہب کا تقابلی مطالعہ، تاریخ پرستی، عمرانیات، آزاد خیالی وغیرہ۔ چنانچہ مستشرقین میں بعض ’’پرخلوص‘‘ لوگ بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کا ذہن ایسا مسخ ہوچکا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ مستشرقین کی بنیادی خامیاں یہ ہیں:
- ۱۔ مذاہب کے مطالعے میں سینہ بہ سینہ چلنے والی روایت کو سمجھنے کے بجائے کتابوں پر تکیہ کرنا۔
- ۲۔ دین کے مستند شارحین کے اقوال کے بجائے اپنی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا۔
- ۳۔ ہر دین اور ہر تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈنا اور ایسے عناصر کو فوقیت دینا جہاں مغرب کی جدیدیت کا رنگ نظر آئے۔
- ۴۔ عقائد تک کو تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھنا۔
- ۵۔ لسانیات کے مطالعے پر زور دینا اور عقائد و احکام کی تشریح لغت کے اعتبار سے کرنا۔
- ۶۔ ادیان کو نظریۂ ارتقاء کی رو سے دیکھنا۔
- ۷۔ ’’تحقیق‘‘ برائے تحقیق میں مصروف رہنا۔ محض ’’واقعات‘‘ کی چھان بین کرنا، چاہے ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوسکے۔
- ۸۔ پرانی کتابیں تلاش کر کے شائع کرنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینی حیثیت کیا ہے؟ دینی معاملات میں قصہ کہانی کی کتابوں تک کو شہادت میں پیش کرنا۔
- ۹۔ سائنس کے طریقے سے مذہب کا مطالعہ کرنے کا زعم۔
- ۱۰۔ دین اور تصوف کو فلسفہ سمجھنا۔
- ۱۱۔ دین کے معاملات میں اخلاقیات پر زور دینا۔
- ۱۲۔ مذہب کی حقیقت نہ سمجھنا۔
- ۱۳۔ عقلیت۔
- ۱۴۔ یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجھنا اور مشرقی ادیان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا۔
- ۱۵۔ خود عیسوی دین بلکہ مغربی تہذیب سے بھی قرار واقعی آگاہی نہ رکھنا اور اس کے باوجود مشرق کی ہر چیز پر محاکمہ کرنے کا دعویٰ کرنا۔
- ۱۶۔ اپنے مطالعہ اور اپنی تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھنا کہ مشرق کا ذہن منجمد ہوگیا ہے اور مغرب کا ذہن برابر ترقی کرتا رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا۔